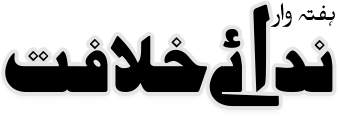(خصوصی مہم) استحکامِ پاکستان کی ٹھوس بنیاد - ادارہ
12 /ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی 1986ء میں شائع شدہ کتاب’’استحکام پاکستان‘‘ سے اقتباسات
استحکامِ پاکستان کی ٹھوس بنیاد
پاکستان کے استحکام کے لیے حقیقتاً اور واقعتاً ٹھوس بنیاد کون سی ہے۔ جسے مضبوط کرنے سے پاکستان مستحکم ہو جائے اوراپنے وجود اور سا لمیت کے خلاف جملہ داخلی اور خارجی حملوں کے مقابلے میں اپنا مؤثر دفاع کر سکے؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ صرف دینی اور مذہبی نقطہ نگاہ ہی سے اہم نہیں ہے، بلکہ خالص مادی اور دنیوی اعتبار سے بھی نہایت اہم ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے اور نہ صرف یہ کہ اس وقت ہم اس میں آباد ہیں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی اِسی سے وابستہ ہے۔ یہ باعزت ہے تو ہم بھی باعزت ہیں اور خدانخواستہ یہ ذلیل ہو جائے تو اصل ذلت ہماری ہو گی، یہ آزاد ہے تو ہم آزاد ہیں، یہ غلام ہو گیا تو اصل غلام ہم ہوں گے، یہ خوشحال ہو گا تو ہم خوشحال ہوں گے اور اس پر تنگی آئی تو اُس تنگی کا شکار ہم ہوں گے۔ گویا یہ کشتی تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں اوریہ ڈوب گئی تو ہم غرق ہو جائیں گے۔ لہٰذاہر پاکستانی کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان کے باعزت بقاء اور اس کے استحکام کے مسئلے پر پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچ بچار کرے۔
تو آیئے اس بات پر غور کریں کہ بالعموم ملکوں کو کن جہتوں سے تقویت ملتی ہے اور کن عوامل کی بناء پر استحکام حاصل ہوتا ہے اور ان میں سے کون کون سے عوامل ہمیں پاکستان کے استحکام کے لیے دستیاب ہیں جنہیں مزید تقویت دے کر ہم پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں۔
اوّلین عامل کو ’’تاریخی عامل‘‘ (Historical Factor) کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی ملک عرصہ دراز سے ایک ہی نام اور ایک ہی سے حدود اربعہ کے ساتھ قائم ہو تو اُس نام اور اُن حدود کو ایک گونہ ’’تاریخی تقدس‘‘ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ اُس کی تقویت کا موجب اور اُس کے استحکام کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر کبھی اس پربحیثیت مجموعی یا اُس کے کسی علاقے پر جزوی طور پر کوئی دوسرا ملک قبضہ کر لیتا ہے تب بھی نہ اُس کا نام بدلتا ہے نہ دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ علاقہ اب اُس ملک کا حصہ نہیں رہا بلکہ قابض ملک کا جزو بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب سے دنیا کی تاریخ انسان کے علم میں ہے اُسی وقت سے چین نامی ملک بھی دنیا میں موجود ہے، اور اُس کا نام بھی ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے اور اُس کی حدود بھی ہمیشہ تقریباً یہی رہی ہیں۔ یہ اِسی کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ جاپان نے چین کے بہت بڑے رقبے پر طویل عرصے تک قبضہ کیے رکھا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ علاقہ ’’چین‘‘ نہ رہا ہو بلکہ ’’جاپان‘‘ بن گیا ہو۔ بلکہ چین چین ہی رہا اور جاپان جاپان رہا اور کہنے میں یہی آتا رہا کہ چین کے اتنے رقبے پر جاپان قابض ہے۔
یہ تاریخی عامل اور یہ تاریخی تقدس پاکستان کو حاصل نہیں ہے اور اِس نام اور اِن حدود کے ساتھ تاریخ انسانی میں کبھی کوئی ملک موجود نہیں رہا۔ بلکہ پاکستان کا تو لفظ آج سے پچاس سال قبل تک دُنیا کی کسی لغت میں موجود ہی نہیں تھا۔
پاکستان کی تقویت کے لیے ’’تاریخی تقدس‘‘ کی قسم کا کوئی عامل موجود نہیں ہے۔
کسی ملک کو تقویت دینے والا دوسرا عامل جغرافیائی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی سرحدیں فطری جغرافیائی حدود (Natural Geographical Boundaries) کی صورت میں ہوں تو اِس سے بھی اُس ملک کو ایک گونہ حفاظت حاصل ہوتی ہے جو اس کی تقویت کی موجب اور اُس کے دفاع میں ممدومعاون ہوتی ہے۔
کلام اقبال کے پہلے اُردو مجموعے کی پہلی نظم کے پہلے شعر میں یہ حقیقت بڑی خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ یعنی ؎
اے ہمالہ! اے فصیل کشور ہندوستان
چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں!
چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ موجودہ ساری سائنسی اور تکنیکی ترقی کے باوجود کوہِ ہمالیہ کی حیثیت بھارت کے شمال میں ایک فصیل کی سی ہے۔ اور اگرچہ تقسیم ہند کے بعد ہمالیہ کے انتہائی مشرقی حصے میں چین اور بھارت کے مابین ایک خونریز جھڑپ ہو چکی ہے، جو نتائج کے اعتبار سے بھارت کے لیے نہایت ذلت آمیز اور رُسواکن ثابت ہوئی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کی پوری تاریخ ایسے کسی واقعے سے بالکل خالی ہے اور اب بھی بھارت کو اِس جانب سے اندیشہ بہت کم ہے۔ اسی طرح1965ء کی جنگ کے ضمن میں ہمیں خود یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ کس طرح بی آر بی کینال بھارت کے بھر پور حملے کے مقابلے میں لاہور کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی تھی۔
ملکوں کو مستحکم کرنے والے تیسرے عامل کو ’’انسانی جذبہ‘‘ کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی ملک یا خطہ ارضی کے رہنے والے انسانوں میں کوئی حقیقی اور واقعی جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ تاریخ کو بھی شکست دے سکتا ہے اور جغرافیہ سے بھی لڑ سکتا ہے، اِس لیے کہ انسان واقعتاً اشرف المخلوقات ہے اور قدرت نے اِس میں بے پناہ قوتیں اور توانائیاں ودیعت کر رکھی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب کسی قوم اور بالخصوص اُس کے جوانوں میں کوئی جذبہ حقیقتاً اور واقعتا پیدا ہو جائے تو اُس کا رخ سوائے مشیت ایزدی اور قدرتِ خداوندی کے دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں پھیر سکتی۔ بقول اقبال ؎
’’عقابی رُوح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزل آسمانوں میں!‘‘
اب اگر ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو انسانی جذبے کی دو ہی قسمیں نظر آئیں گی: ایک قوم پرستانہ جذبہ اور دوسرا مذہبی جذبہ۔ ان میں سے بھی اگرچہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین معجزے تو مذہبی جذبے ہی کے تحت رونما ہوئے ہیں، تاہم کچھ اِس بناء پر کہ موجودہ دنیا میں یہ جذبہ بالعموم کمزور ہی نہیں معدوم کے درجے میں آ گیا ہے۔ اور کچھ موجودہ بحث کی منطقی ترتیب کے تقاضے کے طور پر پہلے ہم ’’قوم پرستانہ جذبہ، کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا اس کی کوئی قسم یا نوع ہمارے پاس بالفعل موجود یا ہمارے لیے ممکن الحصول ہے یا نہیں؟
قوم پرستی کی اقسام کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے یہ حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ موجودہ دنیا میں تمام تر علمی و سائنسی ترقی اور ذہنی و فکری ترفع کے باوجود نسل پرستانہ قومیت کا جذبہ سب سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے۔ عہد حاضرمیں اس کی دو نمایاں ترین مثالیں جرمن قوم پرستی اوریہودی نسل پرستی کی صورت میں موجود ہیں۔ جرمن قوم میں اپنے بارے میں ایک اعلیٰ اور برتر نسل ہونے کے احساس نے اتنا جذبۂ عمل اور قوتِ مقاومت پیدا کر دی ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے بیسویں صدی عیسوی کے دوران جرمنی دو بار شدید ترین تباہی سے دوچار ہوا، لیکن دونوں مرتبہ چند ہی سال کے اندر اندر پھر نہ صرف یہ کہ دوبارہ اپنے پائوں پر کھڑا ہو گیا بلکہ دوسری ہم عصر اقوام اور آس پاس کے ممالک کا ہر اعتبار سے ہمسر ہو گیا بلکہ بعض اعتبارات سے اُن سے بھی بازی لے گیا۔ اِسی طرح یہودی قوم میں بنی اسرائیل کے ’’خدا کی منتخب اور پسندیدہ قوم‘‘ہونے کے احساس نے مقاومت اور مدافعت کی اتنی صلاحیت اور اپنی برتری کے بالفعل اظہار کے لیے بے پناہ محنت اور جدوجہد کا جذبہ پیدا کردیا ہے کہ تاریخ ِ انسانی کے دَوران بارہا انہیں شدید ترین جبر وتشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور بعض مواقع پر تو اِن کے ’’استیصال‘‘اور کلی اور مجموعی خاتمے کی ایسی سرتوڑ کوششیں ہوئیں کہ جن کی کوئی دوسری مثال تاریخ انسانی میں بمشکل ہی مل سکے گی، اِس سب کے باوجود وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور اگر کسی ایک خطے یا ملک سے اُنہیں دیس نکالا مل جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی اور ملک میں قدم جما لیے ہیں۔ چنانچہ اِس صدی کے آغاز میں علامہ اقبال نے اُن کی جس کیفیت کا مشاہدہ بچشم سریورپ میں کیا تھا جس کی تعبیر انہوں نے ان الفاظ میں فرمائی تھی کہ
’’فرنگ کی رگِ جاں پنجۂ یہود میں ہے!‘‘
اُس کے بعد بالخصوص جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں اُن کا جو حشر ہوا اور وقتی طور پر اُنہیں جو نقصان پہنچا اُس کے چند سالوں کے اندر اندر اُنہوں نے بعینہٖ وہی حیثیت امریکہ میں حاصل کر لی۔ چنانچہ آج اسرائیل کی چھوٹی سی مملکت امریکہ ہی کی امداد اور سرپرستی کے بل پر نہ صرف پورے عالم عرب بلکہ پورے عالم اسلام کو ناکوں چنے چبوا رہی ہے۔ اور اِسی پر بس نہیں دُور بیٹھے پاکستان تک کو دھمکیاں دے رہی ہے ۔
اِس سلسلے میں ضمنی طور پر یہ بات بھی سامنے آ جائے تو اچھا ہے کہ یہ بات جو دنیا میں بالعموم کہی جاتی ہے کہ موجودہ دنیا کے دو ملک مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل، تو یہ درحقیقت اسرائیل کی نسل پرستی کو چھپانے کا نہایت شاطرانہ انداز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خالص مذہب کی بنیاد پر دنیا میں صرف ایک ہی ملک قائم ہوا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اسرائیل کی اساس مذہب پر نہیں نسل پرستی پر ہے اور ’’صہیونیت‘‘ اصلاً ایک دینی اور مذہبی تحریک نہیں بلکہ نسل پرستانہ تحریک ہے اور اسرائیل خالص نسل پرستانہ ملک ہے۔
بہرحال پاکستان میں نسلی قومیت کے لیے کوئی اساس موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ برصغیر پاک و ہند نسلی اعتبار سے غالباً پوری دنیا میں سب سے بڑی کھچڑی (بلکہ حلیم!) کی حیثیت رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اُسی کا ایک خلاصہ اِس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں در اوڑی لوگ بھی موجود ہیں (جیسے بلوچستان کے برہوی قبائل) اور آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، اِسی طرح منگول بھی ہیں اور شامی النسل بھی، بلوچ بھی ہیں اور افغان بھی ، حتیٰ کہ شمالی علاقہ جات میں شین بھی ہیں اور بلتی بھی! الغرض یہاں کسی ایک نسل کے لوگ ایسی غالب اکثریت میں موجود نہیں ہیں کہ نسل قوم پرستی کی بنیاد پر ملک کے استحکام کی توقع کی جا سکے۔
نسلی قوم پرستی کے بعد موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قومی جذبہ لسانی قوم پرستی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی بھی دو مثالیں قابل توجہ ہیں: ایک عرب قوم پرستی اور دوسرے بنگلہ قوم پرستی۔
عرب قوم پرستی جو ماضیٔ قریب میں عالم عرب میں ایک زبردست قوت کی حیثیت سے موجود رہا ہے اصلاً ایک لسانی قوم پرستی ہے۔ اِس لیے کہ اس کی اساس نہ مذہب پر ہے نہ نسل پر، بلکہ صرف اور صرف زبان پر ہے۔ چنانچہ اس کے حلقہ بگوش اور علمبردار صرف مسلمان ہی نہیں رہے ہیں بلکہ دانشوروں کی سطح پر اس میں زیادہ بھاری پلڑا عیسائیوں کا رہا ہے، حتیٰ کہ یہودی بھی اس میں شریک رہے ہیں۔ پھر اس میں نسل کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے اِس لیے کہ شمالی افریقہ کے باشندوں میں جہاں عرب آبادکاروں کی اولاد شامل ہے، وہاں قدیم قبطی اور بربرنسل کے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن اِس سب کے باوجود محض زبان کے اشتراک نے اِن سب میں مشترک قومیت کا احساس پیدا کیا اور خواہ اُس کے اساسی فلسفے سے ہمیں کتنا ہی اختلاف ہو، بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عالم عرب نے یورپی استعمار کے خلاف جو جدوجہد کی اور جس کے بل پر اِس استعمار کا جوا اپنے کندھوں سے اُتار پھینکا، اُس کی اصل اساس اِسی لسانی قوم پرستانہ جذبہ پر تھی۔
اِسی طرح پاکستان کے دو لخت ہونے میں جہاں منفی طور پر اولاً بے مقصدیت اور بے یقینی کے خلاء اور بعدازاں مارشل لاء کے رد عمل کو دخل حاصل ہے، وہاں مثبت طور پر جو ہتھیار سب سے زیادہ کارگر اور جو وار سب سے بڑھ کر کاری ثابت ہوا وہ بنگلہ قوم پرستی کا تھا جس کی اساس بنگلہ زبان پر قائم کی گئی تھی۔
حصولِ پاکستان کی تحریک کے دوران تو چونکہ مقابلہ ہندو قوم اور ہندی زبان سے تھا لہٰذا مسلم قومیت اور اُردو زبان تقریباً لازم و ملزوم بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تقریباً مترادف اور ہم معنی ہوگئے تھے۔ لیکن قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان اُردو کے مد مقابل کی حیثیت سے سامنے آ گئی تھی اور خود قائداعظم کی زندگی کے دوران اِس مسئلے نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ اُنہیں اپنی تمام تر علالت اور نقاہت کے باوجود مشرقی پاکستان کا سفر اختیار کرنا پڑا تھا۔ اِسی زمانے کا واقعہ ہے کہ علامہ سید سلیمان ندویؒ کے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے نہایت توہین آمیز رویہ محض اِس بات پر اختیار کیا تھا کہ انہوں نے خالص علمی انداز میں وہاں یہ فرما دیا تھا کہ کچھ عرصہ قبل بنگلہ زبان کا رسم الخط بھی وہی تھا جو عربی، فارسی، اردو، حتیٰ کہ سندھی، بلوچی اور پشتو کا ہے، اور یہ تجویز پیش کی تھی کہ دوبارہ بنگلہ زبان کا رسم الخط اُردو والا ہی اختیار کر لیا جائے تو لسانی بعد و فصل میں کمی آ جائے گی جس سے قومی یک جہتی کو فروغ حاصل ہوگا۔
بہرحال پاکستان کی زندگی کے پہلے پچیس سالوں کے دوران جہاں ایک جانب بے یقینی اور بے مقصدیت کا خلامہیب سے مہیب تر ہوتا چلا گیا اور قومی وملی سطح پر ضعف بڑھتا چلا گیا، وہاں مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان، بنگلہ ادب، بنگلہ تہذیب اور بنگلہ ثقافت کے حوالے سے بنگلہ قوم پرستی قدم جماتا چلاتا گیا۔ اور بالآخر اسی کے منطقی نتیجے کے طور پر ’’بنگلہ دیش‘‘ وجود میںآ گیا اور مشرقی پاکستان کا نام بھی دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا۔
قصہ مختصر یہ کہ ہمارے پاس کل پاکستان اساس پر کسی لسانی قومیت سے پیدا شدہ جذبۂ عمل تو درکنار، تا حال ’’قومی زبان‘‘ کے مسئلے کا حل بھی موجود نہیں ہے ۔
وطن کی اساس پر قومیت کی تشکیل کا تصور زیادہ پرانا نہیں ہے اور اسے عہد جدید کی پیداوار قرار دینا غلط نہ ہو گا۔ تاہم اِس وقت عالمی سطح پر کم از کم نظری اور دستوری و قانونی اعتبار سے سب سے زیادہ چرچا اور سب سے بڑھ کر رواج اِسی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر میں قومیت کے تعین کے ضمن میں وطن ہی کو تقریباً متفقہ طور پر اساس تسلیم کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اِسی کا مظہر ہے کہ ایک موقع پر مولانا حسین احمد مدنی ؒکی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ ’’آج کل قومیں وطن کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔‘‘ جس پرمفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے نہایت سخت اور تیز و تند تنقید کی تھی ۔
اِس کے باوجود چونکہ پاکستان میں کسی قوم پرستانہ جذبہ کی پیدائش اور نشوونما کے لیے نہ اشتراکِ نسل کی بنیاد موجود ہے نہ اشتراکِ زبان کی، لہٰذا اِس کے ضمن میں کم از کم نظری طور پر کسی قوم پرستانہ جذبے کے لیے واحد دستیاب اساس یہی رہ جاتی ہے۔ اور غالباً اسی درجہ بدرجہ نفی کے عمل کا نتیجہ تھا کہ بانی و مؤسس پاکستان قائداعظم محمد علی جناح مرحوم نے 11/اگست 1947ء کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ: ’’عنقریب پاکستان میں نہ مسلمان مسلمان رہیں گے نہ ہندو ہندو رہیں گے، مذہبی اعتبار سے نہیں، اِس لیے کہ مذہب تو اشخاص کا انفرادی معاملہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم کے اعتبارسے ۔‘‘
قائداعظم مرحوم کے ان الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور آیا ان الفاظ کو اُن کے سابقہ بیانات اور اعلانات کی نفی اور اپنے سابقہ مؤقف سے انحراف کا مظہر قرار دیا جائے، یا اُن کے اعصاب پر اُس وقت کے حالات کی پیچیدگیوں اورسنگینیوںسے پیدا شدہ شدید دبائو کا اثر سمجھا جائے؟
پاکستان دو قومی نظریہ کی اساس پر وجود میں آیا تھا، جو وطنی قومیت کے نظریے کی کامل نفی کی حیثیت رکھتا ہے ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ملک قائم تو ہو کسی نظریے کی کامل نفی کی اساس پر اور پھر اس کے استحکام کے لیے وہی نظریہ جڑ بنیاد کا کام دے سکے؟
انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مابین اختلاف و نزاع کی اصل بنیاد کیا تھی؟ کانگریس کے نزدیک مذہب وملت کا معاملہ علیحدہ تھا اور قومیت کا علیحدہ، چنانچہ ہندوستان میں مذاہب بہت سے تھے لیکن اُن سب کے پیروئوں پر مشتمل قوم ایک ہی تھی یعنی انڈین نیشن یا ہندی قوم، جب کہ مسلم لیگ کا مؤقف یہ تھا کہ یہ صورت دوسرے جملہ مذاہب کے پیروؤں کے نزدیک قابل قبول ہو تو ہو کم از کم مسلمانانِ ہند کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اُن کی قومیت کی اساس مذہب پر ہے، لہٰذا وہ ایک علیحدہ قوم ہیں اور اپنے جداگانہ قومی تشخص کے بقاء کی ضمانت کے طور پر علیحدہ ملک کے حق دار ہیں۔
اِس موضوع پر خود قائداعظم محمد علی جناح کے بے شمار بیانات اور اعلانات معروف ہیں۔
’’وطنی قومیت‘‘ کے نظریے پر جو کاری ضرب مصور ِپاکستان علامہ محمد اقبال نے لگائی تھی وہ یقیناً اِس قابل ہے کہ اُسے ذہنوں میں تازہ کیا جائے۔ اِس لیے کہ اُنہوں نے مسلمانوں کے ایک جداگانہ قوم ہونے کے صرف تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی شواہد ہی پیش نہیں کیے تھے،بلکہ ایک ضرب ابراہیمی سے اِس باطل نظریے کے بت ہی کو پاش پاش کر دیا تھا کہ ملکی سرحدیں مستقل قومیتوں کی تشکیل کی بنیاد بن سکتی ہیں اور انسان محض زمینی تعلق کی بناء پر ایک دوسرے سے کٹ سکتا ہے۔ چنانچہ ’’وطنیت (یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے) کے عنوان سے فرماتے ہیں : ؎
’’اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم اور
ساقی نے بِنا کی روشِ لطف و ستم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اِس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
یہ بت کہ تراشیدۂ تہذیب نوی ہے
غارت گر کاشانۂ دین نبویؐ ہے
بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے تو مصطفویؐ ہے
نظارۂ دیرینہ زمانے کو دِکھا دے!
اے مصطفوی! خاک میں اِس بت کو ملا دے!‘‘
قصہ مختصر، وطنی قومیت کا نظریۂ تحریک پاکستان کی نفی ہے اور اس کے فروغ سے پاکستان کی جڑیں مزید کھوکھلی تو ہو سکتی ہیں مضبوط نہیں ہوسکتیں۔
دوسری نہایت اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان خواہ وہ باعمل ہو، خواہ بے عمل بہرحال اُس کے مزاج کی ایک مستقل ساخت ہے اور اُس کی طبیعت کی ایک خاص اُفتاد ہے، جس میں زمین کی پرستش اور ’’وطن‘‘ کے تقدس کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گویا اُس کی شخصیت کا خمیر جس مٹی سے اُٹھا ہے اُس میں ’’حب وطن‘‘ کا مادہ تو ہو سکتا ہے، ’’وطن پرستی‘‘ کا امکان نہیں ہے۔
پروفیسر مرزا محمد منور اِس حقیقت کو اِن خوبصورت الفاظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں کہ ہند و کلچر زمین میں گڑا ہوا اور زمین سے بندھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے یہاں زمین ’’دھرتی ماتا‘‘ کی حیثیت رکھتی ہے اور ’’بھارت کی جے‘‘ کے نعرے سے اُن کے جذبات میں اُبھار اور احساسات میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، جب کہ مسلمان کے دل میں زمین کے مقدس یادیوتا ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے بلکہ اُس کا مزاج’’آفاقی‘‘ ہے اور اُس کے جذبات میں گرمی اور احساسات میں ہلچل ’’اللہ اکبر‘‘ کے نعرے سے ہوتی ہے۔
برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو زیادہ ہی خصوصیت حاصل ہے اور ان کا مزاج کچھ زیادہ ہی ’’آفاقی‘‘ ہے۔ اِس کا ایک ممکنہ سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہاں کوئی دوسری نسلی یا لسانی عصبیت ایسی موجود نہیں تھی جو اُنہیں ایک دوسرے سے باندھ سکتی، لہٰذا اپنی شیرازہ بندی کے لیے انہیں مذہب کی قوت ماسکہ (Binding Force) پر دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہی انحصار کرنا پڑا اور چونکہ اسلام ایک علاقائی مذہب نہیں بلکہ آفاقی اور عالمی مذہب ہے۔ لہٰذا اُن میں ’’آفاقیت‘‘ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہی سرایت کر گئی۔
چنانچہ بیسیویں صدی عیسوی میں مغربی استعمار کے ہاتھوں عالمی ملت اسلامیہ کو جو چرکے لگے اور صدمے سہنے پڑے اور جن مظالم کا نشانہ بننا پڑا، اُن پر سب سے زیادہ درد انگیز نالے اور رقت آمیز مرثیے ہندوستان کے مسلمانوں نے کہے۔ اور اگرچہ وہ خود تو اُن مظالم و مصائب سے گزشتہ صدی کے دوران دو چار ہو چکے تھے اور اب نسبتاً پُر امن ماحول اور قانونی و دستوری نظام میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے مسلمانوں پر ظلم وستم کی خبر آتی تھی، ہندوستان کا مسلمان بالکل اسی شان کے ساتھ تڑپ اُٹھتا تھا جس کا نقشہ اِس شعر میں سامنے آتا ہے: ؎
خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیرؔ
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے!
چنانچہ طرابلس میں مسلمانوں کے جھنڈے سرنگوں ہوئے تو عربی زبان میں دردا نگیز مرثیہ کہا اعظم گڑھ (یوپی) کے ایک اصلاً ہندی اور نسلاً راجپوت مسلمان عالم و عارف کتابِ الٰہی مولانا حمید الدین ؒ نے ؎
(کَیْفَ الْقَرَارُ وَقَدْ نُکِس اَعْلاَمُنَا بِطَرابَلس!!)
’’قرار کیسے نصیب ہو جب کہ ہمارے جھنڈے طرابلس میں سرنگوں کر دیئے گئے۔‘‘
الغرض مسلمانانِ برصغیر پاک و ہند کا مزاج ویسے تو ابتدا ہی سے آفاقی رہا ہے، لیکن اِس صدی میں تو یہ کیفیت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اِس مزاج اور اُفتادِ طبع اور اس انداز فکر و نظر کے وارثِ کامل اور حامل اتم مسلمانانِ پاکستان کے قلب و نظر کی ایسی قلب ماہیت کیسے ممکن ہے کہ زمینی تعلق اتنا مضبوط اور وطن کی پرستش اتنی گہری ہو جائے کہ ایک وطنی قوم پرستی اس کے استحکام کی اصل اساس بن جائے۔
اِس ضمن میں اِس تاریخی عجوبے پر بھی نگاہ رہے تو مناسب ہو گا کہ اِس صدی کے اوائل میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر ایک زبردست عوامی تحریک چلی صرف اور صرف ہندوستان میں اور اس تحریک کی تیزی اور تندی کا عالم یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ پورے برصغیر کی فضا اِس شعر کی صدائے بازگشت سے گونج اُٹھی تھی کہ ؎
’’بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو!‘‘
بلکہ ہندوؤں تک کو اِس تحریک میں شمولیت اختیار کرنی پڑی تھی۔ اِس لیے کہ آنجہانی موہن داس کرم چند گاندھی نے شدت کے ساتھ محسوس کر لیا تھا کہ اگر اِس وقت اِس تحریک کا ساتھ نہ دیا تو پورا پولیٹیکل کیرئیر ختم ہو کر رہ جائے گا۔
تیسری اور آخری لیکن نہایت اہم بات یہ ہے کہ اگر زمینی تعلق ہی کو قومی جذبہ کی بنیاد بنانے پر زور دیا جائے تو اِس سے اتحاد نہیں، انتشار وجود میں آئے گا۔ اِس لیے کہ یہ نظریہ ایک ایسے حیوان کے مانند ہے جو اپنے دشمن کو خود اپنے ہی دودھ سے پالتا ہے۔ چنانچہ ’’وطنی قومیت‘‘ ہی کے بطن سے ’’علاقائی قومیتیں‘‘ جنم لیتی ہیں اور اُسی کی چھاتیوں سے دودھ پی کر پروان چڑھتی ہیں۔
اِس ضمن میں بھارت کا معاملہ اگرچہ پاکستان سے قدرے مختلف ہے کہ لفظ بھارت بھی کئی ہزار سال پرانا ہے اور ’’مہا بھارت‘‘ کا تصور بھی نہایت قدیم ہے۔ جبکہ پاکستان کا تو نام ہی حادثِ محض ہے، اِس کے باوجود ’’ وطنی قومیت‘‘ کے نظریے میں تقسیم در تقسیم کے جو بیج بالقوہ موجود ہوتے ہیں، اُس کا نقشہ وہاں بھی نظر آ رہا ہے اور علاقائی قومیتیں اور مقامی عصبیتّیں نسلی اور لسانی عوامل سے مزید تقویت پا کر نہایت تیزی اور تندی کے ساتھ سر اٹھا رہی ہیں اور بھارتی قیادت کو اپنی ملکی وحدت و سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے پیہم و مسلسل اور شدید و جاں گسل محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اِس پس منظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا معاملہ بے حد نازک اور کمزور ہے۔ اِس لیے کہ پاکستان کا تو تصور بھی پچاس سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں رکھتا، اور کم از کم اِس نام کے ساتھ کسی سیاسی وحدت اور اُس کی عظمت و سطوت کی کوئی تاریخ موجودنہیں، لہٰذا اگر اِس کی اساس پر وطنی قومیت کا راگ الاپا گیا تو اصل تقویت سندھی، بلوچی، پختون اور پنجابی قومیتوں کو حاصل ہو گی۔ اِس لیے کہ اگر فی الواقع زمینی رشتہ ہی مقدس ہے تو ایک سندھی کے لیے سندھ کے وطن ہونے کا تصور زیادہ قریبی بھی ہے اور قدیمی بھی۔ پھر اِس کو تقویت دینے کے لیے خاص طور پر لسانی عامل موجود ہے جو نہایت قوت کا حامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا لفظ بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور اِس کی حدود بھی ہرگز نہ کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں نہ اُن پر مبنی، تو پھر اگر وطن ہی کو ’’پوجنا‘‘ ہے تو سر زمین سندھ کو کیوں نہ ’’پوجا‘‘ جائے۔
اِس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے نہ ’’تاریخی تقدس‘‘ کا عامل موجود ہے نہ ہی ’’جغرافیائی عوامل‘‘ اس کے پشت پناہ ہیں، پھر کوئی نسل، لسانی یا وطنی قومیت کا جذبہ بھی ایسا موجودنہیں ہے جو اِس کے استحکام کے لیے پختہ اساس اور سنگین بنیاد کا کام دے سکے،لہٰذااِس کے استحکام کا کل دارومدار صرف ایک چیز پر ہے اور وہ وہی ہے جس نے اِسے جنم دیا تھایعنی ’’مذہبی جذبہ‘‘۔
اگر اِسے اپنی بقا مطلوب ہے اور یہ کسی دوسری طاقت کا طفیلی یازیردست بن کر نہیں، بلکہ باوقار اور باعزت اور حقیقتاً آزاد اور خود مختار ہو کر باقی رہنا چاہتا ہے تو اِس کے لیے کوئی اور چارۂ کار سرے سے موجود ہی نہیں ہے سوائے اِس کے کہ یہ اِسلام کا دامن تھامے اور اُسی کا سہارا لے۔‘‘
یہ بات ہر اُس شخص کے لیے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے جو کسی بھی وجہ سے پاکستان کے بقاء و استحکام کا طالب اور خواہش مند ہو۔
جو شخص بھی دل سے پاکستان کی بقاء و استحکام چاہتا ہو اُس کے لیے ان شاء اللہ العزیز ہمارا یہ تجزیہ فیصلہ کن ثابت ہو گا اور وہ اس حقیقت کو جان لے گا کہ ا گرچہ عوام کی فلاح و بہبود، انتظامی مشینری کی اصلاح و تطہیر اور مختلف علاقوں کے رہنے والوں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والوں کا اعتماد و اطمینان بھی نہایت اہم اُمور ہیں اور اُن کے بغیر بھی یقیناً پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر موجودہ حالت میں تو اِن کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے۔
تاہم پاکستان کے دوام و استحکام کی اصل اساس یہ چیزیں نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلامی جذبہ ہے اور اگر وہ جلد از جلد بھرپور انداز میں بروئے کار نہ آیا تو باقی تمام چیزوں کی اصلاح کے باوجود پاکستان یا تو اپنی سا لمیت ہی کو برقرار نہیں رکھ سکے گااور اِس کے حصے بخرے ہو جائیں گے۔ یا اگر باقی رہے گا بھی تو کسی دوسری بڑی طاقت کاطفیلی یا زیردست ہو کر۔
وہ مذہبی جذبۂ جو اَب پاکستان کے استحکام کی حقیقی ، واقعی ،مضبوط اور پائیدار بنیاد بن سکتا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے قطعاً مختلف ہے، اُس ’’مذہبی جذبے‘‘ سے جس نے پاکستان کو جنم دیا تھا اور جو آج سے تقریباً نصف صدی قبل تحریک پاکستان کی رُوح رواں بنا تھا۔ راقم قائداعظم مرحوم کے11اگست 1947ء کے جملے کے بارے میں اپنی توجیہہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہے۔
قائداعظم کا وہ قول نہ تو اُن کے سابقہ مؤقف سے انحراف کا مظہر تھا۔ اِس لیے کہ قائداعظم مرحوم خواہ ایک ’’مذہبی شخصیت‘‘ نہ تھے تاہم ہرگز دنیا کے عام سیاستدانوں کے مانند جھوٹے اور فریبی نہیں تھے، اور اُن کے کردار کی مضبوطی، ’’سیرت کی پختگی‘‘ظاہر و باطن کی یکسانیت اور صداقت و امانت کا لوہا اُن کے بدترین دشمن بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح اُن کا وہ متنازعہ جملہ حالات کے وقتی دبائو کے تحت اعصاب کے متاثر ہو جانے کا بھی مظہر نہیں تھا، اِس لیے کہ قائداعظم کے اعصاب ہرگز اتنے کمزور نہ تھے، بلکہ وہ واقعتاً فولادی اعصاب کے مالک تھے اور برے سے برے حالات میں بھی اُن پر کبھی گھبراہٹ یا سراسیمگی کے طاری ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
اُن کے اِس قول کی اصل توجیہہ اور اُن کے سابق مؤقف کے ساتھ اُس کی مطابقت و موافقت کی صورت یہ ہے کہ پیش نظر اوّلاً برصغیر پاک وہند میں بسنے والے مسلمانوں کے دین ومذہب، تہذیب و ثقافت اور سیاسی و معاشی حقوق کی حفاظت و مدافعت تھی، جو قیام پاکستان کی صورت میں بتمام و کمال حاصل ہو گئی اور اِن چیزوں کے ضمن میں ہندوؤں کے نامنصفانہ بلکہ منتقمانہ روّیے سے پیدا شدہ خطرات کا سدِّباب ہو گیا ۔ثانیاً پاکستان میں واقعتاً اسلامی نظام کے بالفعل قیام کے ضمن میں اُن کے پیش نظر ایک خالص جمہوری طریقہ تھا۔ یعنی یہ کہ اگر پاکستان کے مسلمانوں میں جو ایک غالب اور فیصلہ کن اکثریت میں ہیں، واقعتاً اسلام کے ساتھ حقیقی اور واقعی لگاؤ پیدا ہو جائے اور وہ حقیقتاً اور واقعتا ًاسلامی تہذیب و تمدن کے فروغ اور اسلامی قانون و شریعت کے نفاذ و اجراء کے خواہاں بن جائیں تو خالص سیکولر جمہوری نظام بھی اُن کے راستے میں ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اُن کے اجتماعی ارادے‘‘ کے بروئے کار آنے میں ہرگز کوئی چیز مانع نہیں ہوسکتی، لہٰذا فوری طور پر دستوری اور قانونی سطح پر مذہبیت کا راگ الاپنے اور پوری دنیا کو خبردار اورچوکنا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک جمہوری نظام میں قانون سازی کا سارا دارومدار کثرت رائے پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر بالفرض پاکستان میں ایک سیکولر لیکن حقیقتاً جمہوری نظام قائم ہو جائے تو مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو دین ومذہب کی جانب پیش قدمی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔
اب یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو قائداعظم کی اس رائے سے اختلاف ہو اور وہ اِس طریق کار کو اسلامی نظام کے قیام اور قانون اسلامی کے نفاذ و ترویج کے لیے درست اور مؤثر نہ سمجھے، لیکن اِس توجیہہ سے وہ سارے اِشکال حل ہو جاتے ہیں جو اِس جملے کے ظاہری الفاظ سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ کسی انحراف کا کوئی سوال باقی رہتا ہے نہ کسی وقتی اور فوری سراسیمگی کا۔ ھٰذَا مَا عِنْدِی وَالْعِلْمُ عِنْدَاللّٰہِ!